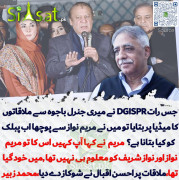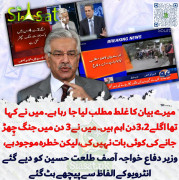بلاشبہ اسلامی علوم کی تدوین تاریخ کا ایک روشن باب ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ پہلی تحقیق ہی کو آخری سمجھ لیا گیا اور انسانوں کی مرتب کردہ کتب کو ہر تنقید سے بالا قرار دے کر تحقیقِ مزید کے دروازے بند کر دئے گئے۔
امام ابو حنیفہ ؒ نے ،جو فقہ اسلامی کے مدّون او ّل ہیں ، اپنی فقہ کو دین اسلام کے مجموعی مزاج کو مدّ نظر رکھتے ہوئے جمہوری انداز میں مرتّب کیا اور ٓزادانہ تحقیق و جستجو پہ زور دیا تا کہ شخصی تقلید راہ نہ پا سکے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کی فقہ کو ایک مستقل مذہب کا درجہ دے کر اس کی تقلید کو ضروری قرار دے دیا جائے گا۔ اسی طرح امام مالکؒ اپنی کتاب مؤطا(جسے انہوں نے خلیفہ منصور کی فرمائش پہ لکھا تھا) کو سلطنتِ عباسیہ کا قانون بنانے پر رضامند نہ ہوئے کیونکہ اس سے تقلید کی راہ ہموار ہو جاتی۔ ان دونو ں جلیل القدر ائمہ نے عباسیوں کا آلۂ کار نہ بننے کی پاداش میں سخت تکلیفیں اٹھائیں ۔ امام ابو حنیفہ ؒ کی وفات کے بعدان کے شاگرد ابو یوسف نے سرکاری عہدہ قبول کر لیا اور ملوکیّت پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ فقۂ حنفی کو سلطنتِ عباسیہ کی سرکاری فقہ قرار دے دیا گیا اور آزادانہ تفقّہ فی الدّین کی راہیں عملًا بند کر دی گئیں۔ یہ اسلام میں تقلیدِ شخصی کا آغاز تھا۔ مشہور حنفی امام، ابوالحسن عبید اللہ کرخی(متوفیٰ ۹۵۲) احناف کا موقف یوں بیان کرتے ہیں
قرآن کی جو آیت اس طریقے کے مخالف ہو جس پر ہمارے اصحاب ہیں، وہ یا تو موؤل ہے یا منسوخ۔ (تاریخ فقہ اسلامی، ترجمہ عبدالسلام ندوی ص۴۲۱)
یہ پڑھ کر آدمی تھرا جاتا ہے کہ انسانوں کی رائےپر قرآن کو یا تو منسوخ کیا جائے یا اس کی اپنے اصحاب کی رائے کے مطابق تاویل کی جائے گی۔
اس کے بعد تدوینِ حدیث کا دور آیا جس میں محدّثین نےروایات کے بحر بے کراں میں اپنی اپنی استعداد کے مطابق غوّاصی کر کے جوگوہر و خذف اپنی کتابوں میں جمع کیے اوران سب پر قال رسول اللہﷺ کی مہر تصدیق ثبت کی اوراسے حدیثِ رسولﷺ کے نام سے امّت کو کر پیش کر دیا ۔ قرآن کے چیلنج فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ(۲:۲۳،۱۰:۳۸) ( تو بنا لاؤ اس طرح کی ایک ہی سورت)۔ کا جواب تو کوئی نہ لا سکا اور نا ہی لا سکے گالیکن صحاح، مسانید، معاجم، جوامع اور سنن کے نام پر روایات کے دفاتر کے دفاتر قلمبند کر دئے گئے اور انہیں مثلہ معہ کے نام پر وحیٔ الٰہی کا مثل قرار دے دیا گیا۔ یوں روایات کے دفاتر نا صرف قرآن کے مقابل لا کر کھڑے کیے گئے بلکہ انہیں قرآن پہ فیصلہ کن حیثیت دے دی گئی، ابو عمرو عبدالرحمن بن محمد اوزاعی اور یحیٰ بن کثیر کےا قوال اس طرز عمل پر حجّت ہیں۔ ابو عمرو عبدالرحمن بن محمد اوزاعی کا قول ہے
الکتاب احوج الی السنة من السنة الی الکتاب
(قرآن حدیث کا محتاج ہے جبکہ حدیث قرآن کی محتاج نہیں)
اور یحیٰ بن کثیر کا قول:
السنة قاضیةعلی الکتاب ولیس الکتاب بقاض علی السنة
( حدیث کو قرآن پہ فیصلہ کن حیثیت حاصل ہے جبکہ قرآن کو حدیث پہ فیصلہ کن حیثیت حاصل نہیں)
جس طرح مسندِ ابو حنیفہ کے نام سے جو مجموعہ حدیث مرتب کیا گیا اس کا امام ابو حنیفہ سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ بعد کے حنفی علما نے اپنے مذہب کے مطابق مرتب کیا، اسی طرح مسندِ احمد بن حنبل جو روایاتِ حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے امام المحدثین احمد بن حنبل متوفیٰ ۲۴۱ ھ سے منسوب ہے لیکن ان کی مرتب کردہ نہیں۔ امام احمد صحاح ستہ کے تمام مصنفین کے شیخ یا شیخ الشیوخ ہیں، مؤطا امام مالک کے علاوہ تقریباً تمام کتب احادیث کے مرتبین نے ان سے استفادہ کیا ہے، وہ علم حدیث میں ایسی مرکز ی حیثیت رکھتے ہیں کہ علم حدیث کا ان بغیر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔
مسندِ احمد ایک ایسا مجموعہ ہے جو ہر فرقے کے حق یا مخالفت میں وافر حصہ رسدی فراہم کرتا ہے، فرقوں کی تشکیل و پشتیبانی میں جتنا حصہ اس کتاب نے ڈالا ہے کوئی اور اس کی شریک و سہیم نہیں ، صوفیا اور روافض نے اس مسند کو اپنے مقصد کے لئے جس طرح استعمال کیا ہے اس کی مثال ملنا ناممکن ہے۔ گو کہ مکذوبہ روایات سے کلیتاً تو حدیث کی کوئی کتاب محفوظ نہیں رہی، لیکن مسند احمد کے علاوہ، المصنف ابن ابی شیبہ اور حاکم کی مستدرک ایسی کتابیں ہیں جن میں ایسی روایات کثرت سے جگہ پا گئی ہیں جنہوں نے فرقہ بندی میں اہم کردار اد کیا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ امام احمد نے اپنی زندگی میں مسند نام کی کوئی کتاب مرتب ہی نہیں کی، اگر کی ہوتی تو تیسری صدی کے دوارن جوصحاح ستہ کے مؤلفین کا دور ہے اس مسند کا تذکرہ ضرور ہوتا۔ امام بخاری متوفیٰ ۲۵۶ ھ نے اپنی تاریخ کبیر میں اپنے استاد امام احمد کا تذکرہ کیا لیکن مسند کا اشارتاً بھی کوئی ذکر نہیں کیا۔ دیگر تمام مؤلفین صحاح ستہ بھی مسند کا کوئی ذکر نہیں کرتے۔ مسند کسی غیر معروف مؤلف کی کوئی چھوٹی موٹی تالیف تو تھی نہیں کہ سب ہی اس سے بے خبر رہتے۔ مسند احمد کا بطور کتاب تذکرہ چھٹی صدی ہجری کے اوائل میں ملتا ہے۔
مسند احمد کی اسناد کو دیکھیں تو یہ امام احمد بن حنبل متوفیٰ ۲۴۱ھ سے عبداللہ بن احمد (۲۱۳ھ ۔ ۲۹۰ھ )سے ابو بکر احمد بن جعفر القطیعی(۲۷۳ھ ۔ ۳۶۸ھ ) سے الحسن بن علی ابن المذہب(۳۵۵ھ ۔ ۴۴۴ھ ) سے ابو القاسم ہبۃ اللہ (۴۳۲ھ ۔ ۵۲۵ھ ) تک آحاد در آحاد چلتی ہیں۔ عبداللہ بن احمدکے بعد راوی مجروح ہیں جبکہ ابن المذہب ضعیف الحدیث ہیں۔ سلسلہ اسناد کوسرسری دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن احمد کی وفات کے وقت ابو بکرقطیعی کی عمر صرف سترہ برس تھی، جبکہ ابن المذہب ، ابو بکرقطیعی کی وفات کے وقت فقط تیرہ سال کے تھے اور ہبۃ اللہ محض بارہ سال کے تھے کہ ابن المذہب چل بسے۔ اور یہ کوئی دو چار روایتوں کا معاملہ نہیں پوری مسند یعنی تیس ہزار روایتوں کی سماعت ہے جو چار نسلوں تک کبار سے صغار تک چلتی رہی، اور ہمارے محدثین نے محض امام احمد کی نسبت کی لاج رکھتے ہوئے ان مکذوبہ و موضوعہ روایات کے انبوہ کو قبول کر لیا، اس معاملے میں ہمارے محدثین نے کیسی چشم پوشی سے کام لیا ہے کہ حیرت و حسرت ہے۔
ابن حجر لسان المیزان میں خطیب بغدادی سے نقل کرتے ہیں کہ ابن المذہب کا قطیعی سے مسند احمد کی سماعت صرف جزوی طور پر درست ہے ، مگر ابن المذہب نے غیر سماعت شدہ اجزا کو بھی سماعت شدہ کے ساتھ ملا لیا۔ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ ابن المذہب روایتوں میں قابل اعتماد نہ تھے۔ ابن حجر خطیب بغدادی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ابن المذہب نےابو عمرو مہدی کے واسطے سےایک حدیث بیان کی تو میں نے کہا کہ ابن مہدی تو یہ حدیث روایت نہیں کرتے، تو ابن المذہب نے ابن مہدی کے نام پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بہت سی احادیث میرے پاس آتی ہیں جو غیر منسوب ہوتی ہیں، تو میں ان کو اپنی طرف نسبت دے دیتا ہوں، اس طرح اصل روایت میں اس نسبت کا الحاق ہو جاتاہے، ابن حجر لکھتے ہیں کہ ابن المذہب کی یہ حرکتیں ان کے معاصرین کو ناپسند تھیں، مگر وہ پھر بھی ان حرکتوں سے باز نہ آئے، لیکن اس سے یہ ضرور ظاہر ہو گیا کہ ابن المذہب ایک متقی آدمی نہ تھے اور انہی کی طرح ان کے شیخ ابو بکر قطیعی بھی، اس وجہ سے مسند احمد میں ایسی ایسی روایتیں داخل ہو گئی ہیں جن کے نہ تو متن درست ہیں اور نہ ہی اسناد۔
اتنا کچھ جان لینے کے بعد کوئی ذی شعور صرف اسناد کی بنیاد پر مسند کی روایات کو قبول نہیں کر سکتا، بلکہ اس کی روایات کی اگر مستند کتابوں سے متابعات مل جائیں تو فبہا، ورنہ وہ مردود ہی ہیں۔